دوستوں قواعد کے بغیر اردو ادب ادھورا ہے ۔ قواعد کے ذریعے اردو زبان کی مشق کی جا سکتی ہے۔ ہمارے اندر اردو زبان کو پڑھنے کی صلاحیت تبھی پیدا ہوگی، جب ہم اردو قواعد کی مکمل معلومات رکھتے ہوں گے ۔ اسی کے تناظر میں ہم یہاں پر اردو قواعد سے متعلق نوٹس فراہم کر رہے ہیں تاکہ اردو زبان کو صحیح سمت دی جا سکے ۔
اردو قواعد
(الف) اسم ، ضمیر ، فعل ، حرف اور اس کی قسمیں ۔
(۱) حرف (Orthegraphy)
کسی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی حرف ہے۔ حرف دراصل آواز کی علامت ہے ۔ دوسرے لفظوں کے مجموعے کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ اردو میں حروف تہجی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ مفرد اور مرکب ۔
dمفرد حروف تہجی مندرجہ ذیل ہیں:۔
ا ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ د ڈ ذ ر ڑ ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ہ ی ے 36=
dمرکب حروف مندرجہ ذیل ہیں۔
بھ پھ تھ ٹھ جھ چھ دھ ڈھ رھ ڑھ زھ کھ گھ لھ مھ نھ 15=
حروف کی قسمیں:۔
تلفظ کے اعتبار سے حروف کی قسمیں :۔
تلفظ کے اعتبار سے حروف کی قسمین مندرجہ ذیل ہیں:۔
ا ، ن ، و ، ہ ، ی 5=
(۱) الف مقصورہ :۔ وہ الف ہے جس کی آواز سادہ ہوتی ہے جیسے ادب، بال ، ہوا ۔
(و) الف ممدودہ :۔ اس پر یہ ( ٓ) علامت ہوتی ہے ، اسے مد کہتے ہیں اور اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے ۔ جیسے : آم، آن، آگ ، آج ، آدم ۔
الف ممدودہ زیادہ تر لفظ کے شروع میں آتا ہے ۔ لیکن عربی کے کچھ الفاظ کے درمیان بھی اس کا استعمال ہوتا ہے جیسے مآل ، قرآن وغیرہ ۔
(۲) ن کی دو قسمیں ہوتی ہیں:۔
(i) نون ظاہر:۔ اس کا تلفظ بالکل ظاہر اور عیاں ہوتا ہے ۔ جیسے جان ، بان، دھان ، نمک ، انصاف وغیرہ ۔
(ii)نون غنّہ :۔ اس کی آواز ناک سے نکلتی ہے ۔ جیسے : آنگن ، پتنگ، پلنگ ۔لیکن یہ نون جب لفظ کے آخر میں آئے تو اس پر نقطہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہاں، نہاں ، جہاں ، نہیں۔
(۳)وائو کی تین قسمیں ہیں:۔
(i) وائو معروف:۔ یہ وائو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے اور اس پر ( ٗ) کی علامت ہوتی ہے جیسے : خوب، بو، سو ، نور ،حور وغیرہ ۔
(ii) وائو مجہول :۔ جسے کھینچ کر نہیںپڑھاجاتا ہے جیسے ، کو ، مول ، اوس، شور ۔
(iii)وائو معدولہ :۔ یہ وائو لفظ میں لکھے ہونے کے باوجود پڑھی نہیں جاتی ۔جیسے : خواب، خواہش ، خورشید، خوش ۔
(۴)’’ہ‘‘ کی دو قسمیں ہیں:۔
(i) ہائے ملفوظی:۔ وہ ’ہ‘ ہے جس کا تلفظ کیاجاتا ہے۔ جیسے گناہ، پناہ، سیاہ وغیرہ۔
(ii)ہائے مختفی:۔اس کی آواز ’’الف ‘‘ کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ جیسے بندہ ، گندہ، رشتہ، قصہ،حصہ، لہجہ ، مردہ، شعبہ ، کہنہ وغیرہ۔
(۵)’’ی‘‘ کی دو قسمیں ہیں:۔
(i)یائے معروف:۔ اس میں ’ی‘ کا تلفظ کھینچ کر کیا جاتا ہے، جیسے پانی، روٹی، گھاٹی، جیت، امیر، غریب ۔
(ii)ہائے مجہول:۔اس کی آواز سادہ ہوتی ہے جیسے گہرے ، پہرے، چہرے، ایک ، ریل، کھیت ، جیل وغیرہ۔
جب کسی لفظ کے درمیان ہائے معروف آتی ہے تو اس کی پہچان کے لیے اس کے بیچ کھڑا زیرکی علامت دے دیتے ہیں۔ جیسے جھیل، گیت ، خورشید وغیرہ ۔
اسم :۔Noun
تعریف:۔کسی شخص ، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے محمود، اصغر ، کلکتہ، ریل ، میز ،کرسی وغیرہ ۔
dبناوٹ کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں:۔
(۱)جامد (۲) مصدر (۳) مشتق
اسم جامد کی تعریف :۔ وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمہ سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے۔
مثال :۔ حرفت ، پھول، باغ وغیرہ ۔
اسم مصدر کی تعریف:۔ وہ اسم ہے جو خود کسی کلمہ سے نہ بنا ہو، مگر دوسرے لفظ سے بن سکتے ہیں۔
مثال :۔ پڑھنا، لکھنا ، چلنا ،دوڑنا وغیرہ ۔
اسم مشتق کی تعریف:۔ وہ اسم ہے جو کسی اور کلمہ سے بنا ہو یا مصدر سے نکلا ہو۔
مثال :۔ پڑھنے والا، لکھنے والا، دوڑنے والاوغیرہ۔
dاسم جامد کی دو قسمیں ہیں:۔
(۱) معرفہ (۲) نکرہ
معرفہ :۔ یہ وہ اسم جامد ہے جو کسی خاص جگہ ، شخص یا چیز کو بنائے ۔
مثال :۔ محمود ، گنگا ، حیدرآباد وغیرہ۔
نکرہ :۔ وہ اسم جامد ہے جس سے عام چیزیں مراد ہوں ۔
مثال:۔ کتاب ، دریا، پہاڑ وغیرہ ۔
dاسم معرفہ کی چھ قسمیں ہیں جو کہ حسب ذیل ہیں:۔
(۱) علم (خاص) (۲) خطاب (۳) لقب
(۴) تخلص (۵) کنیت (۶) عرف
(۱) اسم علم (اسم خاص ) :۔ کسی شخص ، جگہ یا کسی خاص چیز کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں ۔
جیسے عرفان ، تاج محل، کلکتہ وغیرہ ۔
(۲) خطاب :۔کسی شخص کو شہنشاہ وقت یا حکومت یا کسی امراء ونواب کی طرف سے جو اعزازی نام دیاجاتا ہے اسے ’’خطاب ‘‘ کہتے ہیں۔
جیسے ۔ سر، خان بہادر ، وقار املک وغیرہ۔
(۳)لقب:۔ یہ اسم نام کو کہتے ہیں جو کسی کو اس کی خوبی یا برائی کی وجہ سے دیاگیا ہو ۔
جیسے :۔ بلبل شیراز، ملکۂ ترنم ، شیر بنگال وغیرہ
(۴) تخلص :۔ شاعر اپنے نام کے علاوہ جو مختصر نام رکھتا ہے۔ اسے تخلص کہتے ہیں۔ تخلص کا استعمال اکثر غزل کے آخری شعر میں کیاجاتا ہے۔
جیسے :۔ شاہ ، جگر ، فراق ، ساحر ، مجروح وغیرہ ۔
(۵)کنیت:۔ اس نام کو کہتے ہیں جو وہاں باپ ، بیٹے بیٹی یا کسی اور تعلق سے مشہور ہو جائے کنیت کہلاتا ہے ۔
جیسے:۔ ابن مریم، ام کلثوم ، ابن خالد وغیرہ ۔
(۶) عرف :۔ اصل نام کے علاوہ محبت یانفرت کی وجہ سے جونام پڑجاتا ہے۔ اسے عرف کہتے ہیں۔
جیسے:۔ بنٹی، ببلو ، کلو وغیرہ۔
dاسم نگرہ کی چھ قسمیں ہیں:۔
(۱) اسم ذات (عام) (۲) اسم مصغر (۳) اسم مکبر
(۴)اسم آلہ (۵) اسم صوت (۶ ) اسم ظرف
(۱) اسم عام :۔ یہ وہ اسم ہے جو اپنی شناخت کے اعتبار سے معروف ہے ۔ یا یوں کہاجائے کہ جو فرد، جگہ یا شہر کانام ہے ۔
جیسے :۔ شاہد ، پٹنہ، بیماری وغیرہ
(۲) اسم مصغر:۔ یہ لفظ صغر سے بنا ہے ۔ اس کے معنی چھوٹائی کے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی بڑے لفظ کو چھوٹا کرکے دکھائے ، اسم مصغر کہلاتا ہے ۔ جیسے دیگ سے دیگچی ، باغ سے باغیچہ ، ناول سے ناولٹ وغیرہ۔
(۳)اسم مکبر:۔ یہ کبر سے بنا ہے جس کے معنیٰ بڑا کے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا کرکے دکھائے اسم مکر کہلاتا ہے ۔
جیسے :۔ راہ سے شاہراہ ، تھالی سے تھال، چھری سے چھرا وغیرہ ۔
(۴) اسم آلہ :۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی آلہ یا اوزار یا ہتھیار کے نام کوظاہر کرے۔
جیسے :۔ آری، کترنی ، تھرما میٹر وغیرہ۔
(۵) اسم صوت:۔ صوت کے معنیٰ ہے آواز چنانچہ وہ لفظ جو کسی مخصوص جاندار کی آواز کو ظاہر کرے۔ اسم صوت کہلاتا ہے ۔
جیسے:۔ ٹن ٹن، میائوں میائوں، جھم جھم وغیرہ۔
(۶) اسم ظرف :۔ وہ اسم یا نام جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے۔ اسم ظرف کی دو قسمیں ہیں ۔
(۱) اسم ظرف مکان (۲) اسم ظرف زبان
dاسم ظرف مکان :۔وہ اسم ہے جو کسی جگہ کا تصور پیش کرے جیسے گوشالہ ، کتب خانہ، چراگاہ وغیرہ۔
d اسم ظرف زمان :۔ وہ اسم جو کسی وقت یا زمانے کو ظاہر کرے ۔ جیسے صبح ، شام ، ہفتہ وغیرہ ۔
dضمیر۔(Pronoun)
تعریف:۔ وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں ۔ ضمیر کہلاتے ہیں۔
جیسے :۔ وہ ، ہم ، تم ، اس نے ، میرا ، تمہاراوغیرہ ۔
dضمیر شخصی کی تین قسمیں ہیں۔
(۱) ضمیر متکلم (۲) ضمیر حاضر یامخاطب (۳) ضمیر غائب
(۱) ضمیر متکلم :۔ یہ وہ ضمیر ہے جو بات کرنے والا اپنے نام کی جگہ لاتا ہے ۔
جیسے :۔میں، ہم، ہم لوگ
(۲) ضمیر مخاطب :۔ یہ وہ ضمیر ہے جو اس شخص کے لیے لایا جائے جو موجود ہو ۔
مثلا:۔ تم ، تم لوگ، آپ، آپ لوگ۔
(۳) ضمیرغائب :۔ یہ وہ ضمیر ہے جو ایسے شخص کے لیے لایا جائے جو موجود نہ ہو ۔
مثلا:۔ وہ، وہ لوگ وغیرہ ۔
(۲) ضمیر استفہامی :۔ یہ وہ ضمیر ہے جو سوال کرنے کے لیے بوالاجائے۔
جیسے :۔ کون آیا، کیا کھائو گے وغیرہ۔
(۳) ضمیر اشاری :۔ وہ ضمائر جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
جیسے :۔ یہ خریدوگے یا وہ ، اس میں یہ اشارے کئے گئے ہیں۔ یہ قریب اور دور کی چیزوں کے لیے اشارہ کرنے کے لیے بولاجاتا ہے۔
(۴) ضمیر موصولہ:۔ وہ ضمیر جو اسم کی جگہ استعمال ہو مگر اس کے ساتھ مزید ایک جملہ ہوتا ہے جس میں اس اسم کے بارے میں کچھ کہا گیا ہو ۔
جیسے:۔ وہ لڑکا جو کل آیا تھا پکڑا گیا۔ چور جس کو میں پہچانتا ہوں بتا دوں گا ۔ تمہارا دوست جو سعودی میں ہے آیا ہے ۔ ان جملوں میں ’جو‘ ،’جس کو‘ضمائرموصولہ ہیں۔ یہ بالترتیب اپنے سے پہلے آنے والے اسم ’لڑکا‘،’چور‘،’دوست‘ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔
(۵) ضمیر تنکیری :۔ یہ وہ ضمیر ہے جو غیر معین شخص یا چیز کے لیے بولاجائے ۔
جیسے کوئی آیا ہے۔ کچھ کھائوگے وغیرہ ۔
dصفت (Adjective)
وہ کلمہ جس سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو صفت کہلاتا ہے ۔ اور جس اسم کی اچھائی ، برائی یہ کلمہ ظاہر کرتا ہے وہ موصوف کہلاتا ہے ۔
جیسے :۔ کالی ، گندہ ، ٹوپی ، چھوٹے بچے وغیرہ
صفت، صفت ، صوف صفت موصوف
(۱) صفت کی چار قسمیں ہیں:۔
(۱) صفت مشبہ (۲) صفت نسبتی (۳) صفت عدد (۴) صفت مقداری
(۱) صفت مشبہ:۔ وہ صفت ہے جس سے کسی وصف کا ذات میں شامل ہونا پایا جائے یہ وصف اس شخص یا چیز کی اندرونی حالت یا کیفیت کو بھی ظاہر کرتا ہے ۔
جیسے:۔ اپاہج ، پیلا،ٹھوس، پھوہڑ، ہنس مکھ، بیوقوف ،ہونہار ، موٹاوغیرہ۔
(۲) صفت نسبتی:۔ وہ صفت ہے جو کسی شخص یا چیز کا لگائو(نسبت) کسی دوسرے شخص یا چیز سے ظاہر کرے ۔
مثلاً :۔ پشاوری ٹوپی ، بنگالی رسگلے ، کشمیری شال، دہلوی، عیسیوی، مصری اور نورانی صفت نسبتی ہیں۔
(۳) صفت عددی: وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد، رتبہ یاترتیب کے لحاظ سے درجہ شمار معلوم ہو ۔ جیسے چار لڑکے، دوکرسیاں ، کچھ لوگ ، پانچواں مکان وغیرہ ۔
(۴) صفت مقداری:۔ وہ صفت جس سے کسی چیز کی مقدار معلوم ہو یہ صفت صرف ان چیزوں کے لیے آتی ہے جن کو گنتی میں نہ بتاکر ناپ ، وزن یا مقدار میں بتایا جاتا ہو ۔
جیسے: تین کلو گھی، مٹھی بھرچاول، سیر بھر چینی، گزبھرکپڑا ، تھوڑا سا دودھ، چلو بھرپانی وغیرہ۔
dفعل ـ:۔ (Verb)
تعریف:۔ جس سے کسی چیز کا ہونا یاکرنا زمانہ کے ساتھ سمجھا جائے۔ اسے فعل کہتے ہیں۔ کسی کام کو بھی فعل کہتے ہیں لیکن اس میں زمانہ نہیں ہوتا ۔
جیسے :۔ کھانا ، پینا، آنا، جانا، رونا، ہنسنا وغیرہ ۔
(فاعل) کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ جیسے حامد آیا ، انور گیا، ان جملوں میں (آنا ، جانا ) کرنے والے حامد اور انور فاعل ہیں۔
(مفعول) جس پرکام کااثر پڑے اسے مفعول کہتے ہیں:۔ جیسے حامد روٹی کھارہا ہے ۔ شکیلہ دودھ پی رہی ہے۔ ان جملوں میں کام کرنے والوں(حامد ، شکیلہ ) کے کاموں (کھانا ، پینا) کا اثر روٹی اور دودھ پر پڑھ رہا ہے ۔ یہ ان جملوں میں مفعول ہیں۔
فعل کی قسمیں زمانے کے لحاظ سے ۔
فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع ، فعل امر ، فعل نہی
آپ جانتے ہیں کہ زمانے تین ہیں۔(۱) ماضی(۲) حال (۳) مستقبل
زمانہ ماضی:۔ وہ زمانہ یا وقت جو گزر چکا ہو۔
زمانہ حال :۔ موجودہ زمانہ یعنی وہ وقت جس میں کام جاری ہو۔
زمانہ مستقبل :۔ آنے والے زمانہ یا وقت کو زمانہ مستقبل کہتے ہیں۔
اب آپ زمانہ کے لحاظ سے فعل کی چھ (۶) قسموں کے بارے میں پڑھیں گے ۔
(۱) فعل ماضی :۔ وہ کام (فعل ) جو گزرے ہوئے زمانے میں کیاگیا ہو ۔ جیسے شہناز آئی ، میں نے خط لکھا تھا۔ وہ پڑھ رہا تھا۔
(۲) فعل حال:۔ وہ فعل جو موجودہ زمانہ میں کیا جارہا ہو ۔ جیسے محمود لکھتا ہے۔ لڑکیاںکھیل رہی ہیں۔ تم گاتے ہو۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ فعل کے ساتھ تا، تی، تے ،یا، رہا ، رہی ، رہے آتا ہے ۔ جیسا کہ فعل حال کی مثالوں سے واضح ہے۔
(۳) فعل مستقبل:۔ وہ فعل جوآنے والے زمانہ میں کیاجائے گا مثلاً ہم جائیں گے ۔ ٹرین آئے گی ۔ تم کامیاب ہوگے۔
(۴) فعل مضارع :۔ اس میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کی جھلک پائی جاتی ہے۔ یعنی دونوں زمانوں کے لیے بولاجاتا ہے ۔ جیسے وہ آئے تو میں جائوں، اگر وہ نہ ملے توآپ آجائیں ۔ طلبا پڑھیں تو کامیاب ہوں وغیرہ۔
ان مثالوں میں ’’آئے ، جائوں، ملے، آئیں، پڑھیں، کامیاب ہوں فعل مضارع ہیں۔
(۵) فعل امر:۔ امر کے معنیٰ حکم کے ہیں یہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کاحکم دیاجائے یا درخواست کی جائے جیسے پانی پلائو، سبق یاد کرو، جائیے۔ تشریف رکھئے ، فعل امر ہیں۔
(۶)فعل نہی:۔ وہ فعل جس میں کسی کام کے لئے منع کیاجائے ۔ اس میں فعل کے ساتھ ’مت‘ یا ’نہ ‘ آتا ہے جیسے مت رو۔ بارش میں مت بھیگو ، دھوپ میں نہ کھیلو ، شور نہ کرئیے وغیرہ۔
فعل (مصدر ) کی قسمیں
(۱) فعل معروف (۲) فعل مجہول (۳) فعل لازم (۴) فعل متعدی (۵) فعل ناقص
(۱) فعل معروف: ۔ وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا، معلوم ہو جیسے ۔سہیل آیا، طلعت پڑھتی ہے ۔ وہ کھیلے گا۔
(۲) فعل مجہول :۔ اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا مثلاً کپڑے دھل گئے ۔ آٹا پسا، دروازہ کھلا، مکان بن گیا وغیرہ ۔ کپڑے کا دھلنا، آٹے کا پسنا، دروازے کا کھلنا ۔ یا مکان بن جانا خود بخود نہیں ہوا بلکہ یہ کام کسی کے ذریعہ کیاگیاہے۔ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں’’فعل مجہول‘‘ کہتے ہیں۔
فعل لازم :۔ وہ فعل جس کا اثر صرف فاعل تک ہی محدود رہے یعنی وہ صرف اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پورا ہوجاتا ہے ۔ جیسے۔ وہ آیا ، بچی روتی ہے ، نجمہ ہنسے گی وغیرہ۔
فعل متعدی:۔ وہ فعل جس کا اثر فاعل کے علاوہ کسی اور (مفعول ) شخص یا چیز پر پڑے جس جملہ میں یہ فعل ہوتا ہے وہ صرف فاعل سے پورا نہیں ہوتا بلکہ مفعول کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ مثلاً اس نے کھایا۔ راشد اخبار پڑھتا ہے ۔ احمد خط لکھے گا۔
فعل ناقص:۔ فعل ناقص وہ فعل ہیں جس میں کسی کام کا کرنا نہیں پایا جاتا بلکہ ’ہونا‘ پایاجاتا ہے ۔ اس لیے اس کا کوئی فاعل نہیں ہوتا بلکہ اسم بجائے فاعل کے مبتدا کہلاتا ہے اور جملہ کابقیہ جز جو حالت یا کسی طرح کی خبر دیتا ہے ’’خیر‘‘ کہلاتا ہے ۔ جیسے۔ رامو چور ہے ۔ لڑکے میدان میں ہیں۔ خالد ذہین تھا۔ وہ بیمارتھی ۔ میں چھوٹا نہیںہوں۔
مندرجہ بالاجملوں میں ’ہے‘، ’ہیں‘، ’تھی‘، ’تھا‘، ’ہوں ‘فعل ناقص ہیں۔
تشبیہ:۔ (The Simile)
شبلی نعمانی نے اپنی کتاب ’’شعرالعجم‘‘ میں تشبیہ اور استعارہ کی تعریف اس طرح بیان کی ہے۔
’’تشبہیات اور استعارات کلام کے حسن کو بڑھانے کے لیے زیورات کا کام کرتے ہیں۔ ان کے ذریعہ اصل معاملہ کی تصویر بخوبی سامنے آجاتی ہے ۔ جس قدر یہ دونوں اپنی اصلی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں ۔ اتنی ہی ان میں اصلی حسن باقی رہتا ہے ۔ لیکن بغیر تھوڑے بہت مبالغہ کے استعارہ یا تشبیہ کامقصد پورا نہیںہوتا۔‘‘
تشبیہ کی تعریف:۔ تشبیہ کالغوی معنیٰ مشابہت کے ہیں۔
کسی چیز کو کسی چیز کے مشابہ یا ہم شکل قرار دینا ۔ مثلاً چاند چہرہ، پتھر جیسا دل ، یاقوت جیسے ہونٹ وغیرہ۔
جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اس کو مشتبہ اور جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اس کو مشبہ بہ کہتے ہیں۔ اس طرح مذکورہ بالاتشبیہوں میں ’’چہرہ ، دل ، ہونٹ۔ مشبہ اور چاند ،پتھر ،یاقوت مشبہ بہ ہوئے۔
میر تقی میر کے اس شعر میں دیکھئے کتنی خوبصورت تشبیہ ہے :۔ ؎
نازکی اس کے لب کی کیا کہیے
پنکھڑی اک گلاب کی سی ہے
اس شعر میں محبوب کے لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی ’لب ‘ اور گلاب کی پنکھڑی مشبہ بہ ہے۔ تشبیہ کے لیے لازم ہے کہ اس میں مشبہ اور مشبہ بہ ہوں۔
dتشبیہات دو طرح کی ہوتی ہیں:۔
(۱)مفرد تشبیہات (۲) مرکب تشبیہات
(۱) مفرد تشبیہات :۔ اس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جاتا ہے ۔
مثلاً چہرہ کو پھول ، آفتاب ،آئینہ اور ماہتاب سے اور دل کو شیشہ ، پتھر ،ماہی اور کنول وغیرہ سے تشبیہہ دینے کومفرد تشبیہات کہیں گے۔
(۲) مرکب تشبیہات:۔ میں ایک بات کو کہنے کے لیے دو چیزوں کاذکر ایک ساتھ کرتے ہیں اور ان کو دو الگ چیزوں سے مشابہت دیتے ہیں۔ مثلاً
میدان جنگ میں گرد وغبار کے درمیان تلواریں اس طرح چمک رہی تھیں جیسے شب میں ستارے ٹوٹ رہے ہوں۔
استعارہ :۔
استعارہ لفظ مستعار سے بناہے جس کے معنیٰ ہوتے ہیں ’’ادھار لینا‘‘ لیکن اصطلاح میں کسی لفظ کو اس کے اصلی معنیٰ کے علاوہ دوسرے کسی معنیٰ میں استعمال کرنے کو’’استعارہ ‘‘ کہتے ہیں۔ ان دونوں معنوں کے درمیان اگر تشبیہی لگائو ہے تو وہ استعارہ کہلائے ۔ ورنہ مجازمرسل ۔ جیسے معشوق کے لیے ’’کافر‘‘ خوش کلام کے لیے ’’بلبل ‘‘ ۔ بہادر کے لیے ’’شیر‘‘ اور حسین کیلئے ’’ماہ رو‘‘ وغیرہ کا استعمال استعارہ کہلائے گا۔ مثلاً ہم یہ کہیں کہ ’’شیرو! دشمن کے چھکے چھڑا دو‘‘ تو یہاں شیر اپنے اصلی معنیٰ میں نہ استعمال ہوکر بہادر کے معنیٰ میں استعمال ہوا ہے ۔ اس لیے شیرو استعارہ ہوا۔ اقبال کی نظم’’جگنو‘‘ میں استعارہ کا استعمال دیکھیے ۔ ؎
چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی
نلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں
اہم بات:۔ تشبیہ میں کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند یا ہم شکل بتایا جاتا ہے جبکہ استعارہ میں ایک چیز کو بالکل اس کے اصلی معنیٰ سے ہٹ کر دوسرے معنیٰ میں لیاجاتا ہے۔
استعارہ میں تین چیزوں کاہونا ضروری ہے:۔
(۱) مستعارضہ :۔ اس چیز کو مستعارمنہ کہتے ہیں جس سے کچھ مانگا جائے۔
(۲) مستعار لہٗـ:۔ اس چیز کو جس کے لیے مانگا جائے مستعار لہ کہتے ہیں۔
(۳) مستعار:۔ وہ چیز جو استعارے میں مانگی گئی اسے مستعار کہتے ہیں۔
مثلاً :۔ موہن کو اس کی بہادری کی وجہ سے شیر کہہ کر مخاطب کریں تو شیر مستعار منہ ،موہن مستعار لہ ، اور بہادری مستعار کہلائے گی۔
مجاز مرسل :۔
جب کسی لفظ کے حقیقی معنیٰ کو ترک کرکے اس کو کسی مجازی معنیٰ میں استعمال کریں تو وہ ’’مجاز مرسل ‘‘ کہلائے گا بشرطیکہ اس لفظ کے لغوی اور مجازی معنیٰ میں تشبیہی تعلق نہ ہو ورنہ تشبیہی تعلق ہونے کی صورت میں وہ ’’استعارہ‘‘ کہلائے گا۔
جیسے :۔ نالابہہ رہا ہے۔ اس مثال میں نالا سے مراد پانی ہے۔ چوں کہ دونوں میں تشبیہی تعلق نہیں ہے اور ’’نالا‘‘ اپنے لغوی معنیٰ سے ہٹ کر مجازی معنیٰ میں بولاگیا ہے ۔ اس لیے نالا کا یہاں استعمال ’’مجاز مرسل‘‘ کہلائے گا۔
کنایہ :۔
کنایہ کے معنیٰ ہیں بات کو پوشیدہ ڈھنگ سے کہنا۔ علم بیان کی اصطلاح میں اس لفظ یا الفاظ کو کہتے ہیں جو موصوف کے لیے بطور صفت بادشاہ استعمال کیا جائے۔ ان کو مجازی معنیٰ کے علاوہ حقیقی معنیٰ میں بھی لے سکتے ہیں۔
کنایہ کی مثال :۔ ؎
ساقی وہ دلے ہمیں کہ ہوں جس کے سبب بہم
محفل میں آب وآتش وخورشید ایک جا
مذکورہ بالاشعر میں آب، آتش ،خورشید یہ تینوں کنایہ ہیں کیوںکہ ساقی سے اشارتاً شراب طلب کی ہے جس میں یہ تینوں صفات مجازی معنوں میں موجود ہیں۔
صنائع وبدائع
(۱) لف ونشر :۔ شعر میں پہلے چند چیزوں کو ایک ترتیب سے بیان کرنا پھر ان کی مناسبت سے وضاحت کرنا، لف ونشتر کہلاتا ہے ۔‘‘
لف کے معنی ہیں لپیٹنا اور نثر کے معنیٰ ہیں پھیلانا ۔
؎ نہ ہمت نہ دل ہے نہ قسمت نہ آنکھیں
نہ ڈھونڈا ، نہ سمجھا، نہ پایا ، نہ دیکھا
(غالب)
؎ تیرے رخسار وقد وچشم کے ہیں عاشق زار
گل جدا، سروجدا ، نرگس بیمار جدا
اس شعر میں رخسار کی مناسبت سے گل ، قد سے سرو اور چشم کی مناسبت سے نرگس کوبیان کیا ہے۔
dلف ونشر کی دو قسمیں ہیں۔
(۱) لف ونشر مرتب (۲) لف ونشر غیر مرتب
(۱) لف ونشر مرتب:۔ اگر ترتیب نشر ، لف کے مطابق ہو تو اسے لف ونشر مرتب کہتے ہیں ۔
مثلاً ؎ جس کی چمک ہے پیدا جس کی مہک ہویدا
شبنم کے موتیوں میں ،پھولوں کے پیرہن میں
پہلے چمک اور مہک کاذکر ہے اور پھر اسی مناسبت سے موتیوں اور پھولوں کا ۔
(۲) لف ونشر غیر مرتب :۔ اگر ترتیب مختلف ہو تو لف ونشر غیر مرتب کہتے ہیں ۔
؎ ایک سب آگ ایک سب پانی
دیدہ ودل عذاب ہیں دونوں
ترتیب مختلف ہے آگ اور پانی کی مناسبت سے ترتیب دل ودیدہ ہونی چاہیے تھی۔
(۲) صنعت تلمیح :۔ تلمیح سے مراد شعر یا کلام میں کسی مشہور قصے ، واقعہ ، کردار ، شخصیت یامذہبی روایت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تلمیح کے الفاظ بظاہر مختصر ہوتے ہیں ۔ لیکن اس کے پیچھے پورا قصہ یاپوری تاریخ ہوتی ہے۔ مثلاً ۔
کیا وہ نمرود کی خدائی تھی
بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا
(۳) تلمیع:۔ جب شعر کا ایک مصرع ایک زبان میں ہو اور دوسرا کسی اور زبان میں۔
بہار زندگی برباد کردی
قیامت اے دلِ ناشاد کردی
(۴) حسن تعلیل:۔
تعلیل کے معنیٰ ہیں وجہ متعین کرنا یا وجہ بیان کرنا۔ اگر کسی چیز کے لیے کوئی ایسی وجہ بیان کی جائے ،جوچاہے واقعی نہ ہومگر اس میں کوئی شاعرانہ جدت ونزاکت ہو اور بات واقعہ اور فطرت سے مناسبت بھی رکھتی ہو تو اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ ؎
سب کہاں کچھ لالہ وگل میں نمایاں ہوگئیں
خاک میں کیاصورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہوگئیں
لالہ وگل کے زمین سے ابھرآنے کی وجہ سے یہ بتائی ہے کہ حسینوں کو زمین میںدفن کردیاجاتا ہے تو حسن فنا نہیں ہوتا بلکہ لالہ وگل کی شکل میں پھر نمودار ہوجاتا ہے حالانکہ یہ وجہ نہیں۔
(۵) تجنیس :۔کلام میں دو یازیادہ الفاظ ایسے لانا جوتلفظ یا تحریر میں مشابہ ہوں اور معنیٰ میں مختلف ہوں۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔
(i) تجنیس تام:۔ جب دو لفظ حروف کی تعداد ترتیب اور اعراب کے لحاظ سے بالکل ایک ہوںاورمختلف معنی رکھتے ہوں تو اسے تجنیس تام کہتے ہیں۔
مثلاً:۔ ڈالی (بمعنیٰ شاخ ڈالی، ڈالنا سے ماضی)
؎ چمن میں کس نے الٰہی نگاہ ڈالی آج
جوکھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج
؎ سب سہیں گے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی
پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی
(ii)تجنیس ناقص وزائد:۔ جب دو ایسے لفظ آئیں جن میں سے ایک میں دوسرے کی نسبت ایک حرف شروع یا آخر یا درمیان میں زائد ہو جیسے ۔زور، زر، کوہ، شکوہ ، بات اور نبات۔
؎ زور وزر کچھ نہ تھا تو بارے میرؔ
کس بھروسے پہ آشنائی کی
(میر)
(۶)تنسیق الصفات :۔ کس موصوف کی متواتر کئی صفات ذکر کرنا جیسے گھوڑے کی تعریف میں کہاہے۔
کہکشاں تنگ، آسماں رنگ، ابرسایہ برق تگ
تیز دم آتش قدم گیسو لجام ابرورکاب
(۷) سوال وجواب:۔ شعر میں سوال وجواب کے ذریعہ مکالمہ کی صورت پیدا کرنا۔
؎ پوچھا کہ طلب، کہا قناعت
پوچھا کہ سبب، کہا کہ قسمت
(دیا شنکر نسیم )
(۸)صنعت ترصیح :۔ شعر کے دونوںمصرعوں میں ترتیب کے ساتھ ایسے الفاط لائے جائیں جو ہم وزن اور ہم قافیہ ہوں۔
مثلا۔ ؎ تیرا انداز سخن شانۂ زلف ایہام
تیری رفتار قلم جنبش بالِ جبریل
(غالب)
(۹) سیاقتہ الاعداد:۔ اعداد کو بالترتیب یا بلاترتیب کلام میںذکر کرنا جیسے :۔
ع دوتین ٹکڑے سر کے ہوئے سل کے چار پانچ (انشا)
؎ چہرئہ ہروش ہے ایک سنبل مشکفام دو
حسنِ بتاں کے دور میں ہے سحر ایک شام دو
(۱۰)تضاد :۔ شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال ایک ساتھ کیا جائے جس میں بہ اعتبار معنیٰ تضاد پایا جائے جیسے ۔ آگ اور پانی ، عرش اور فرش ۔ ؎
ہونا جہاں کا اپنی آنکھوں میں نہ ہونا
آتا نہیں نظر کچھ جاوے نظر جہاں تک
(۱۱)ایہام تضاد:۔ کلام میں دو ایسے معنیٰ کا جمع کرنا جو باہم متضاد یا متقابل نہ ہوں لیکن جن الفاظ کے ساتھ ان کو تعبیر کیا جائے ان کے حقیقی معنوں میں تضاد ہو ۔
جب کلام میں دو ایسے الفاظ لائے جائیں جو معنیٰ کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیںمثلا دن اور رات ، صبح اور شام ، سیاہ اور شفید ۔ ؎
یاں کے سپید وسیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے
رات کو رو رو صبح کیا اور دن کو جوں توں شام کیا
(میر)
اس میں سپید وسیہ ، رات اور دن، صبح اور شام میں تضاد ہے۔ ؎
جوآکے نہ جائے وہ بڑھاپادیکھا
جو جاکے نہ آئے وہ جوانی دیکھی
(انیس)
(آکے ، جاکے، جائے ، آئے ، بڑھاپا، جوانی متضاد لفظ ہیں)
(۱۲) مراعاۃ النظیر:۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کلام میں ایسے الفاظ جمع کیے جائیں جن کے معنیٰ میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نسبت واقع ہو مگر یہ نسبت تضاد اور تقابل کی نہ ہو۔ مراعات النظیر کو تناسب توفیق ، تلفیق بھی کہتے ہیں۔
رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے
نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں
(غالب )
ماخذ : بحوالہ:(۱) اصناف سخن اور شعری ہیئتیں از شمیم احمد
(۲)ادبی اصناف از گیان چند جین
(۳)فن شعر و شاعری اور روح بلاغت ازپروفیسر حمید اللہ شاہی
(۴) قواعد اردو از مولوی عبد الحق
(۵) اردو قواعد از ڈاکٹر شوکت سبزواری

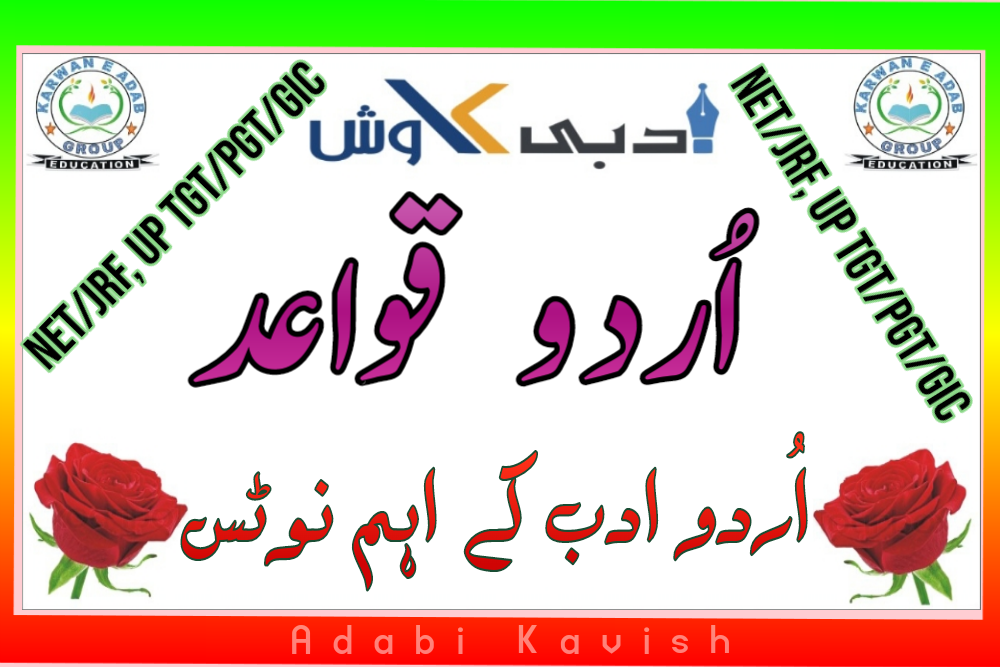
Naina Afrin
September 29, 2023 at 7:06 pmYa makhfi or ya malfuzi ki misale mil sakti hai